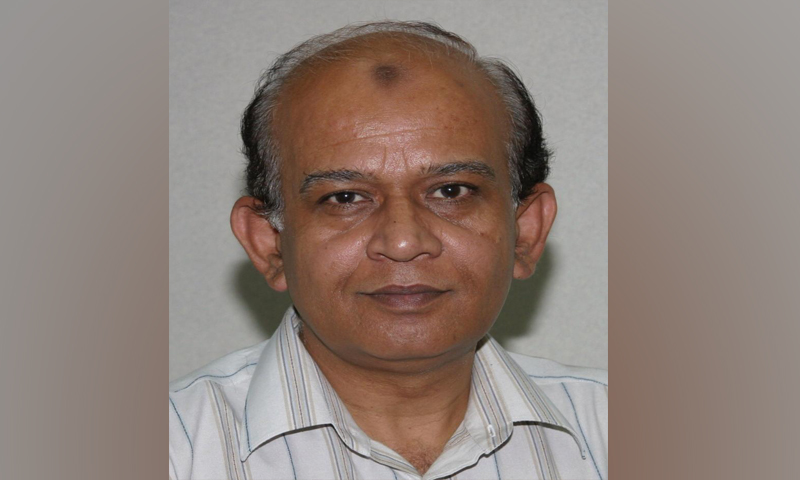ماضی کا دور بہت ہی مامون قسم کا تھا۔ عالم یہ تھا کہ خواتین بلا خوف و خطر خریداری کرنے کے لیے مارکیٹ وغیرہ چلی جاتی تھیں۔ موبائل شوبائل تو تھے نہیں اس لیے راہ چلتے اک بٹوے کے سوا کسی شے کی چھینا جھپٹی یا چوری چکاری کا کوئی خدشہ دامن گیر نہیں ہوتا تھا۔ آج کل تو صورت حال یہ ہے کہ مرد بھی گھر سے نکلتے وقت خوفزدہ رہتے ہیں کہ پتا نہیں واپسی مقدر میں ہے یا نہیں کیونکہ موبائل یا بٹوہ چھیننے والوں کو مزاحمت یا اپنے ’’کام میں مداخلت‘‘ بالکل پسند نہیں۔ ڈاکو حضرات بے گناہ شہریوں کو عموماً ’’پستول دکھا کر‘‘ لوٹتے ہیں اور اگر ’’ڈکیتی‘‘ کے دوران لٹنے والے کی غیرت جاگ جائے تو وہ ’’پستول چلا کر‘‘ لوٹتے ہیں۔ پس لٹنے کے لیے محفوظ طریقہ کون سا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کی چنداں ضرورت نہیں۔
ہمیں وہ وقت اچھی طرح یاد ہے، جب ہم نے کالج جانا شروع کیا۔ ہمارے پاس موٹر تھی، نہ موٹرسائیکل اور نہ ہی سائیکل چنانچہ ہم بس کے ذریعے ہی کالج جایا کرتے تھے۔ آج کی بسوں اور ان میں سفر کرنے والوں کا حشر دیکھ کر ماضی کے ’’مامون دور‘‘ کی یادیں ہمارے ذہن میں کچوکے لگاتی ہیں۔ کیا دور تھا۔ ہم گھر سے استری شدہ کپڑے پہن کر نکلتے تھے اور یقین کیجیے، بلا مبالغہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم بس کے ذریعے جب کالج پہنچتے تو ہمارے کپڑوں کی استری قائم رہتی تھی۔ بسیں بے شک تعداد میں کم تھیں مگر ان کے نخرے بہت تھے۔ اس زمانے میں بس اسٹاپ ہوا کرتے تھے۔ وہاں ایک بورڈ نصب ہوتا تھا جس پر اسٹاپ کا نام درج ہوتا تھا۔ قریب ہی کنکریٹ کا سائبان ہوتا تھا جس کے سائے میں پتھر یا لکڑی کے بینچ یا کرسیاں موجود ہوتی تھیں۔ یہ سائبان دو حصوں میں منقسم ہوتا۔ ایک حصے میں لکھا ہوتا، ’’مستورات کے لیے‘‘ جبکہ دوسرے حصے میں ’’مردوں کے لیے‘‘ کی عبارت تحریر ہوتی۔ یہ بس اسٹاپ نہ صرف پر سکون بلکہ سماجی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہوتا تھا کیونکہ اس دور میں اکثر ازدواجی بندھنوں کا موجب یہی بس اسٹاپ ہوا کرتا تھا۔ ہم اس سائبان کے ’’مردان خانے‘‘ میں جا بیٹھتے۔ بس اپنے وقت پر آتی۔ دروازہ کھلتا، خاکی وردی پہنے کنڈکٹر نمودار ہوتا۔ پہلے اترنے والوں کو موقع دیا جاتا پھر لوگ بس میں سوار ہوتے۔ کنڈکٹر جب اطمینان کر لیتا کہ اب بس میں سوار ہونے والا کوئی نہیں تو وہ خود بس کے پائدان پر قدم جماتا اورگلے میں لٹکی سیٹی بجا دیتا۔ پھر بس کا دروازہ بند کرتا اور بس چل پڑتی۔ کنڈکٹر ہم سے پوچھتا، بابو جی! کہاں جائیں گے؟ ہم اسے اسٹاپ کا نام بتاتے تو وہ ہمیں کرائے کی رقم سے آگاہ کرتا۔ ہم پیسے دیتے اور وہ ٹکٹ پنچ کر کے ہمیں تھما دیتا۔ منزل آتی اور ہم نشست سے اٹھ کر بس سے اتر جاتے۔
آئیے! اب ایک نظر دورِ حاضر کی ٹرانسپورٹ پر بھی ڈالتے ہیں جو لوگوں کے لیے کسی ’’عذاب‘‘ سے کم نہیں۔
آج کل کی بسوں میں نہ دروازہ ہوتا ہے نہ کنڈکٹر کی وردی۔ مسافروں کو ٹکٹ دینے کا سلسلہ تو عرصہ ہائے دراز سے مفقود ہو چکا ہے۔ مسافروں سے کرائے کے لیے استفسار آج بھی کیا جاتا ہے مگر الفاظ ذرا مختلف اور ایسے ’’تیز دھار‘‘ ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ میں ہی دل کی گہرائیوں میں اتر کر دوران خون میں خطرناک حد تک تیزی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ گیدڑ کالونی سے بھینس کالونی جانے کے لیے منی بس میں سوار ہوئے۔ ابھی پائدان پر دونوں پیر بھی نہ رکھ پائے تھے کہ بس چل پڑی۔ قبل اس کے کہ ہم سڑک پر گرتے، ایک انجانے ہاتھ نے ہمیں اس طرح بس کے اندر دھکیلا جیسے مویشیوں کو باڑے میں دھکیلا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ یہ شخص کنڈکٹر نما فرائض ادا کرنے پر مامور ہے کیونکہ اس نے ہم سے کچھ یوں استفسار کیا کہ ’’آں! کدر جائے گا چا چھا؟‘‘ ہم نے کہا کہ بھینس کالونی۔ اس نے کہا کہ 10روپیہ دیونی۔ ہم نے کہا کتنا کرایہ ہے، دس روپے؟ جواب ملا ’’ارے بڈا! تیرے کو سنائی نئیں دیتا کیا؟‘‘ ہم نے دس کا نوٹ نکال کر اسے تھمایا اور اس نے اگلے ہی لمحے ہمیں اس جملے کے ساتھ ایک اور دھکا دیا کہ ’’بیچ سے آگے ہو جوان‘‘۔ بس چونکہ ’’مِنی‘‘ تھی اس لیے ہمیں قدرے جھک کر کھڑے ہونا پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کنڈکٹر نے اگلے دروازے سے لے کر پچھلے دروازے تک کا ایک ’’طوفانی‘‘ دورہ کیا۔ اس دوران بس میں کھڑے مسافروں کی ’’اکھاڑ پچھاڑ‘‘ ہوئی اور دھکم پیل میں ہمارا چشمہ گر گیا۔ اسے اٹھانے کے لیے جھکے تو جیب سے بٹوہ نکل کر لوگوں کے قدموں میں جا گرا۔ ہم نے پاس کھڑے شخص سے کہا کہ ذرا پیر ہٹائیے ہمارا بٹوہ گر گیا ہے۔ وہاں تو کچھ نہیں ملا البتہ اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے ہمیں دور سے بٹوہ دکھاتے ہوئے کہا کہ انکل یہی ہے ناں۔ ہم نے کہا جی ہاں! شکریہ۔ بہر حال کسی نہ کسی طرح ہم بھینس کالونی پہنچے۔ چشمہ ناک پر ٹکایا تو پتا چلا اس کی کمانی ایک ہی رہ گئی تھی۔ بٹوہ دیکھا تو پتا چلا کہ اسے تمام پیسوں سے فارغ کرکے ہمیں لوٹایا گیا تھا۔ ہمارے سر کے بال منی بس کی دھکم پیل میں تتر بتر ہو چکے تھے۔ استری شدہ سفید شلوار قمیص پہن کر گھر سے نکلے تھے مگر اب لباس پر جگہ جگہ کالے، پیلے اور مٹیالے دھبے نظر آ رہے تھے۔ شکنوں کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہم نے یہ کپڑے گھڑے سے نکال کر زیب تن کیے ہوں۔ یوں ہم چشمہ تڑوا کر، بٹوہ خالی کروا کر فقیروں جیسے حلیے میں اپنے دوست کے ہاں پہنچے۔ ان کے بچے ہمیں دیکھ کر یہ شور مچاتے بھاگ کھڑے ہوئے کہ مما! فقیر گھر میں گھس آیا ہے تاہم شکر ہے کہ ہمارے دوست اور ان کی اہلیہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ واپسی پر ہم نے کہا کہ ’’بھیا! ذرا کچھ پیسے ہوں تو دیجیے گا، دراصل کسی نے میرے بٹوے میں سے پیسے نکال لیے ہیں۔ انہوں نے ہمیں 100روپے ادھار دیے اور کہا، ’’برادر! پھر کب آئیں گے‘‘؟ ہم مسکرا دیے اور دل ہی دل میں چلا کر کہا کہ ’’کبھی نہیں‘‘۔ یوں بچپن میں بس کا سفر ہمارے لیے واہ تھا جو بڑھاپے میں آہ بن گیا۔
سچ پوچھیں تو صرف بس یا منی بس کا سفر ہی کیا، گزشتہ 3دہائیوں میں سیاسی، سماجی، اخلاقی اور تعلیمی اقدار جو ’’واہ‘‘ کے زمرے میں آتی تھیں، آج ’’آہ‘‘ بن چکی ہیں۔ ایسے میں کیا یہ کہنا درست نہیں کہ ’’واہیں بن گئیں آہیں؟
خوش آمدید! اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں
اپنا پاسورڈ ريکور کريں
Daily Jasarat News is proudly powered by WordPress